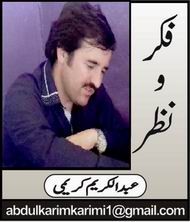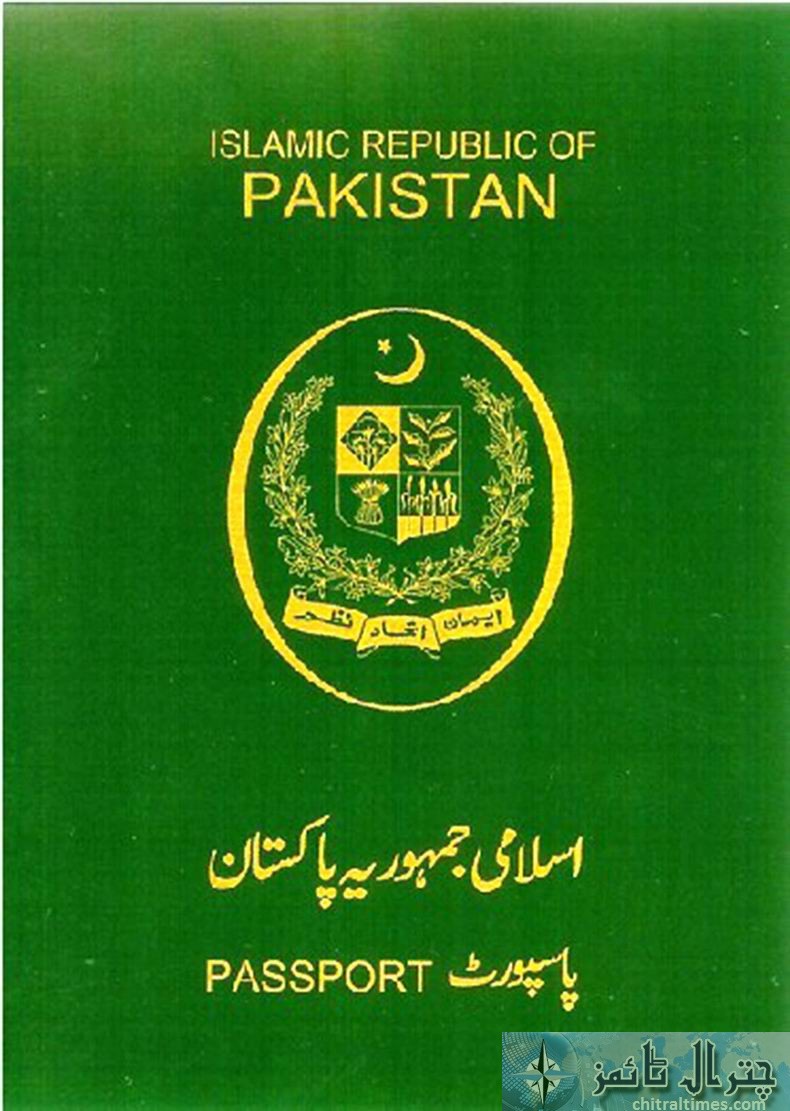یادیں یہ کس کی ساتھ ہیں بارات کی طرح………..عبد الکریم کریمی
کل یوں ہی دِل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی۔ جیسے بہار کی شرارتی ہوا ہرے بھرے درختوں میں سما جائے اور اُس کے پتوں میں کھلبلی سی مچ جائے۔ اُس یاد نے جب میرے اکھڑتے ہوئے سانسوں پر اپنا نرم ہاتھ رکھا تو مجھے قرار سا آگیا لیکن میں جانتا تھاکہ یہ قرار عارضی ہے۔ جُدائی کا درد ناقابلِ بیان ہے۔ تنہائی کسی عفریت کی مانند میرے سامنے منہ کھولے کھڑی ہے اور میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اُس کھائی میں گرتا جارہا ہوں جس کا نچلا حصہ دلدل ہے۔
پہلی بار میں نے آفس کی سیڑھیوں پر تمہیں دیکھا۔ اُس وقت تم زرد رنگ کے لباس میں ملبوس سرسوں کا کھیت معلوم ہو رہی تھیں۔ انٹرویو سے قبل تم کافی گھبرائی ہوئی تھیں اور دورانِ انٹرویو تم نے بال پین مضبوطی سے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ انٹرویو کامیاب رہا اور یوں تم ہمارے دفتر کا حصہ بن گئیں۔ پھر میں روز تمہیں آفس کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے دیکھنے لگا۔ جب پہلی بار میں نے تمہیں لنچ کی پیش کش کی تو تم نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ مجھے یاد ہے اُس پیش کش کو ٹھکرانے کے چند دن بعد تک تم مجھ سے نظریں چراتی رہی تھیں۔
مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بار ہم لنچ کر رہے تھے تو میری تمام توجہ تم پر مرکوز تھی۔ جب میں نے خاموشی سے تمہاری اُنگلی پکڑی تو تم نے گھبرا کر کہا: ’’میرا ہاتھ چھوڑیں۔‘‘
میں نے ہنستے ہوئے کہا تھا: ’’پاگل! میں نے ہاتھ نہیں، تمہاری اُنگلی پکڑی ہے۔‘‘
یہ سن کر تم ہنس پڑیں۔ بے ساختگی اور لا اُبالی پن کا ایک ریلا آیا اور مجھے بہا کر لے گیا۔ دوستی سے انسیت اور انسیت سے محبت تک کے اُس سفر میں تم خاموش رہیں اور میں بولتا رہا۔ برات والے دن جب تم اسٹیج پر دُلہن بنیں میرے پہلو میں بیٹھی تھیں۔ اُس وقت میں نے آہستگی سے کہنی مار کر کہا تھا: ’’کیا آپ میرے ساتھ لنچ کرنے چلیں گی؟‘‘
اُس وقت تم اپنی ہنسی نہیں روک پائیں۔ اسی وقت کیمرے کی فلیش چمکی اور وہ پُرمسرت لمحہ تصویر کی صورت میں قید ہوگیا۔ مجھے یاد ہے تمہاری والدہ نے اُس وقت تمہیں غصے سے گھورا تھا۔ پہلی بار جب میں تمہارے ساتھ تمہارے میکے اور اپنے سسرال پہنچا تو مجھے خصوصی پروٹوکول دیا گیا۔ جب تمہاری بہن نازلی نے میرا جوتا چھپا کر مجھ سے پانچ ہزار روپے مانگے تو تم فوراً بول اُٹھی تھیں: ’’پانچ ہزار کیوں؟ صرف پانچ سو روپے ملیں گے۔‘‘
یہ سن کر نازلی نے حیران ہو کر تمہیں دیکھا اور بولی: ’’آپی! اتنی جلدی بدل گئیں!‘‘
تم ہنس دیں اور میں تمہیں دیکھتا رہا۔
شادی کے بعد تم نے ملازمت کے خیال کو اُٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور کیچن میں جا کھڑی ہوئیں۔ پہلی بار تم نے جو کھیر پکائی تھیں۔ سچ بتاؤں! وہ جلی ہوئی تھی لیکن میں نے کبھی اس بات کا تمہارے سامنے ذکر نہیں کیا۔ ہم بہت خوش تھے اور وقت کو جیسے پر سے لگ گئے تھے۔ شادی کے چند سال بعد جب ہمارے گھر میں ننھے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی تو نہ جانے کیا ہوا کہ پورا ملک ہی مالی بحران کی زد میں آگیا۔ گرانی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی اور دوسری جانب انہی دنوں تمہارے دِل میں ’’اپنے گھر‘‘ کی خواہش انگڑائیاں لینے لگی تھی۔ مجھے تمہاری خواہش کا احترام تھا۔ ہم نے کچھ نہ کچھ بچت کر کے شہر سے دور ایک نئی آبادی میں زمین خریدی۔ اُس وقت تمہاری آنکھوں کی چمک قابل دید تھی۔
وقت گزرتا گیا اور تمہارے بیٹے کا قد تم سے اونچا ہوگیا۔ جب ہم اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ اپنے نئے گھر میں داخل ہوئے تو مجھے یوں لگا تھا جیسے تم خوشی سے بے ہوش ہو جاؤگی۔ دوسرے دن جب میں آفس سے لوٹا تو تم اپنے صاحبزادے کے ساتھ گھر سجا چکی تھیں۔ گرد میں اٹی اپنی محبت کو دیکھ کر میں ہنس دیا۔ جب تم نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو خود بھی بے ساختہ ایک قہقہہ لگایا۔ وہ قہقہہ محبت اور ممتا سے لبریز تھا۔
اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر تم ہر معاملے میں پیش پیش تھیں۔ جوڑا کس رنگ کا ہونا چاہیے، پھول کدھر رکھیں، شادی کا سامان کب پہنچانا ہے، دُلہن کا میک اپ کہاں سے کرانا ہے۔ تم مسلسل مصروف تھیں۔ میں مسکراتا ہوا تمہیں دیکھتا رہا۔ اسٹیج پر جب میرے اور تمہارے بیٹے فیضی نے اپنے باپ کی طرح اپنی شریکِ حیات کو کہنی ماری تو میں حیران رہ گیا۔ تب پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں بوڑھا ہوگیا ہوں اور میرے آدھے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اسی پل مجھے پہلی بار تمہارے چہرے کی جھریاں بھی واضح دکھائی دیں۔ اس خیال نے مجھے دُنیا و مافیہا سے بے نیاز کر دیا۔ شادی، مہمان اور شور! سب کہیں ماضی میں چلا گیا۔ بس تم اور میں رہ گئے۔
’’کتنے سال بیت گئے عروج؟‘‘ تمام ہنگاموں سے آزاد ہونے کے بعد میں نے تمہیں مخاطب کیا تو تم مسکرادیں۔ تقدس میں ڈوبی وہ مسکراہٹ میرے ذہن پر نقش ہوگئی۔ مجھے یاد ہے۔ ہماری بہو نے بھی تمہاری طرح پہلی بار جو کھیر پکائی تھی وہ جل گئی تھی لیکن فیضی مزے سے اسے کھاتا رہا۔ اس پل مجھے یقین ہوگیا کہ ہم دونوں بوڑھے ہوگئے ہیں۔
پھر تم بیمار رہنے لگیں۔ اُس رات سخت سردی تھی۔ میں چھت پر بیٹھا موم پھلی چھیل رہا تھا اور تم بادلوں میں چھپے چاند کو تک رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں تم پر کپکپی طاری ہوئی تو میں نے سردی سے بچانے کے لئے تمہیں چادر اوڑھادی۔ میں نے خود تمہارے لئے چائے بنالی(میں تم سے اچھی چائے بناتا ہوں) جسے پیتے ہوئے تم کسی گہری سوچ میں غرق ہوگئیں۔
’’آپ اب بوڑھی ہوگئی ہیں محترمہ!‘‘ میرے اس جملے سے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی لیکن اس مسکراہٹ میں وہ چمک اور خوشی کی لہر نہیں تھی جس کا میں عادی تھا۔ میں خوف زدہ ہوگیا۔ مجھے لگا کہ کوئی شے تمہیں مجھ سے دور کھینچ رہی ہے۔ میرا یہ خوف حقیقت ہی تھا۔ اپنے پوتے کی پیدائش تک تو تم چاق و چوبند رہیں لیکن پھر…………!!
اسپتال کی عمارت میں مکمل سناٹا تھا اور راہ داریوں میں ہوا کے گزرنے سے بڑی خوفناک آواز پیدا ہو رہی تھی۔ پہلے میں بھی سردیوں کے موسم سے لطف اندوز ہوتا تھا لیکن اس بار یہ موسم مجھ پر بھاری گزرا۔ میں اپنے ہاتھ بغلوں میں دبائے تمہیں مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ اور تم اپنے بستر پر خاموش اور لا تعلق سی لیٹی تھیں۔ پھر میں ماضی میں کھو گیا۔ مجھے وہ رشتہ یاد آیا جس میں بندھنے سے قبل ہم نے دوستی سے انسیت اور انسیت سے محبت کا سفر طے کیا تھا۔ میں نے شرارتی لہجے میں تمہیں مخاطب کیا: ’’کیا آپ میرے ساتھ لنچ کریں گی؟‘‘
پہلے تم حیران ہوئیں اور پھر مسکرا دیں۔ میں اسپتال کے کینٹین سے کولڈڈرنک اور بریانی لے آیا۔ اگرچہ ڈاکٹر نے تمہیں اس قسم کی چیزیں کھانے سے منع کیا تھا لیکن تم نے میری خوشی کی خاطر پرواہ نہیں کی۔ اُس رات چاند اسپتال کی کھڑکی سے جھانکتا رہا اور چاندنی میں نہائے اُس کمرے میں ہمارے ہلکے ہلکے قہقہے گونجتے رہے۔
دوسرے دن تمہاری طبیعت بگڑ گئی۔ فیضی اور بہو نے کمرے کے ڈسٹ بن میں پڑے کولڈڈرنک کے کین دیکھ لئے تھے۔ وہ دونوں بھی مجھ پر غصہ ہو رہے تھے اور تم اُنہیں سمجھا رہی تھیں کہ یہ سب میں نے تمہارے اصرار ہی پر کیا تھا۔ اُس وقت تمہیں دیکھتے ہوئے میں خیالوں میں کھو گیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ تمہاری آنکھوں میں پیار کی شبنم تھی اور سانسوں میں گلابوں کی مہک! اسپتال، ڈاکٹر اور بہو! ہر شے ہر منظر پس منظر میں چلا گیا۔ صرف تم اور میں رہ گئے۔
تم اسپتال سے واپس توآگئیں لیکن تمہاری طبیعت نہیں سنبھلی۔ وقت گزرتا گیا اور تم کمزور ہوتی گئیں۔ تمہاری بے ساختہ مسکراہٹ بھی کہیں غائب ہوگئی۔ آخری بار تم اُس وقت مسکرائیں جب ہمارا چھے سالہ پوتا جیمی اپنی رپورٹ کارڑ لئے بھاگتا ہوا آیا اور تمہارے بستر پر چڑھ گیا۔
’’دادو! میں فرسٹ آیا ہوں۔‘‘ اس نے جوش سے کہا تو تمہاری آنکھوں کی خوشی ناقابلِ بیان تھی جو نمی کی صورت باہر آنے کی منتظر تھی۔ تم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔
وہ کہنے لگا: ’’دادو! میرے گفٹ؟‘‘
تم ہنس دیں اور جیمی تمہارا پرس کھول کر اپنا گفٹ تلاش کرنے لگا۔
پُرنم آنکھوں کے ساتھ جب ہم تمہیں قبر میں اُتار رہے تھے تو جیمی میرا ہاتھ تھامے حیران کھڑا تھا۔ ’’دادو کہاں جارہی ہیں بابا؟‘‘ اس نے اپنے باپ سے سوال کیا۔
’’کہیں نہیں۔‘‘ فیضی نے آہستگی سے جواب دیا جیسے اُس کے حلق میں کچھ پھنس سا گیا ہو۔
شروع میں تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ تم چلی گئی ہو لیکن پھر وقت نے مجھے احساس دلایا کہ اب میں تنہا رہ گیا ہوں اور مجھے تنہا رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔
آج جب میں تمہاری قبر کے سرہانے کھڑا ہوتا ہوں تو یوں ہی کوئی کھوئی ہوئی یاد میرے دِل میں سما جاتی ہے اور قبرستان میں لگے درختوں کے پتوں میں کھلبلی سی مچ جاتی ہے۔ تمہاری یاد جب میری اکھڑتے ہوئے سانسوں پر اپنا نرم ہاتھ رکھتی ہے تو مجھے قرار سا آجاتا ہے لیکن میں جانتا ہوں یہ قرار عارضی ہے اور یہ کھوئی ہوئی یاد ہے۔